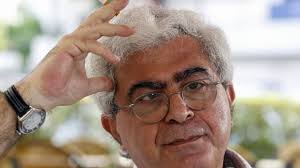تبریز احمد
جس کے پاس علم ہے اسی کے پاس لاٹھی ۔ جس کے پاس لاٹھی ہے اسی کے پاس بھینس۔ یعنی علم طاقت کا ذریعہ ہے، اور طاقت ظلم، قبضہ اور تسخیر کا۔ سائنسی دریافت کے آغاز کے دور میں جب فرانسس بیکن نے کہا نالیج از پاور، تو اس کا مطلب یہی سمجھا گیا کہ سائنسی علوم اور دریافت کے ذریعہ کائنات کی تسخیر کی جا سکتی ہے، جنگل، پہاڑ، ہوا، ندی الغرض ہر چیز پرانسانی تسلط قائم ہو سکتی ہے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ جس کو بعد میں ترقی کا نام دیا گیا۔ لیکن دراصل کائنات کی تسخیرمیں انسان کی تسخیر کی خواہش ہی مضمر تھی، جس کی طرف اشارہ انگریز مصنف نے اپنی کتاب ابولیشن آف مین میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
یہیں سے طاقت کے ایک دوسرے پہلوکا اشارہ ملتا ہے، جو سماجی ہے اور جس کی تفصیلی نشاندہی فرانسیسی فلسفی میشیل فوکو نے اپنی مختلف تحریروں میں کی ہے۔ یعنی علم کے ذریعہ صرف عالم جمادات، نباتات، حیوانات پر ہی نہیں بلکہ انسانوں کو بھی تسخیر کیا جاتا ہے، اسے ایک ڈوسائل جسم یا زومبی بناکر۔ انسانوں پر یہ طاقت کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ خود انسان اپنی پہراداری کرنے لگتا ہے۔(ڈسپلین اینڈ پنش، فوکو) ارگس کوئی اور نہیں بلکہ خودانسان اپنا ارگس بن جاتا ہے۔ آپ کا جسم آپ کی جاسوسی کرنے لگتا ہے۔ یعنی اس غلامی کے لئے کسی جیل اور اس کے پہرادار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ علم کی طاقت کے اس اظہار کو استعماری دور میں تہذیب آموزی کا خوشمنا نام دیا گیا۔ جس نے استعماریت کے ہر گناہ پر پردہ ہی نہیں ڈالا، بلکہ اس کو جائز، اور مستحب بھی قرار دیا۔
انسانوں کو اپنے بس میں کرنے کی طاقت علم تبھی دے سکتا ہے جب یہ علم مخصوص لوگوں کے پاس ہو۔ یعنی علم پر مخصوص لوگوں کا قبضہ ہو۔ کچھ خاص لوگوں کی جاگیر ہو۔ اگر سب کو سب کا علم ہے تو کون کس کو تسخیر کرے گا۔ اسی لئے انسانی تاریخ میں علم ہمیشہ کچھ مخصوص لوگوں کی ہی جاگیر رہی ہے اور انہیں لوگوں نے ہماری سماجی، سیاسی اور ثقافتی اصول مرتب کئے ہیں ۔ یوروپ کے نشاۃ ثانیہ سے پہلے علوم پر جاگیرداری مذہبی طبقہ کا تھا، پھر علمی دھماکہ کے بعد یہی جاگیرداری فرانسیسی انقلاب کے بطن سے پیدا ہوئے نئے مڈل کلاس کے پاس چلا گیا۔ پھر اس کلاس نے مادی اور فکری دونوں حیثیتوں سے دنیا پر نوآبادکاری شروع کی اور دنیا پر سرمایہ داری کا ایک انوکھا جال بچھا دیا۔
علم سے پیدا شدہ اس طاقت کے بے بہا بے جا استعمال نے دنیا میں سماجی اور کائناتی دونوں حیثیتوں سے بھیانک تباہی مچائی ہےاور اب بھی مچا رہی ہے۔ ہم نے ترقی کی تیز رفتار گاڑی پر سواربظاہر خوشحالی کی طرف اس تیز رفتاری سے دیوانہ وار بھاگے کہ خود سے آگے نکل گئے اور پتہ ہی نہیں چلاکہ مشین ہمارے بس میں ہے یا ہم مشین کے بس میں ہیں۔ اس تیز رفتار ترقی کو مذہبی اور علمی جواز بھی فراہم کیا گیا، جب ویبر نے کہا کہ قدرتی وسائی خدا کی طرف سے انسانوں کو دی گئی لامحدود الہی نعمت ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال عین منشا خداوندی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی فکر کا لازمی نتیجہ موحولیاتی آلودگی کی صورت میں ظاہرہوا اور ہو رہاہے۔ ماحولیاتی تبدیلی آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ترقی کی اس تیز رفتاری کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہو چکا ہے اس کا پورا پورا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔
مزید یہ کہ اس علم (سائنس) کی مدد سے ہمیں زہریلی گیس کا پتہ چلا لیکن ہم نے اس کا کیا کیا؟فرانس نے ۱۸۰۳ میں انقلاب ہیتی کے دوران پکڑے گئے جنگی قیدیوں کو اس زہریلی گیس سے دم گھونٹ کر مارڈالا، جرمنی نے ۶۰۰۰ یہودیوں کو گیس چیمبر میں مارڈالا۔ اسی علم کی مدد سے ایٹم کی طاقت کا پتہ چلا اور امریکہ نے اس سے ایٹم بم بناکر دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان کے دو شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کو پلک جھپکتے ہی راکھ بنا ڈالا۔ جس کا ذکر ایمانول ہرتیج ایک منٹ کی خاموشی میں کچھ اس طرح کرتے ہیں
نو مہینے کا مون (خاموشی) ہیروشیما اور ناگا ساکی کے مرتکوں (مردوں) کے لئے، جہاں موت برسی، چمڑی زمین فولاد اور کنکریٹ کی ہر پرت کو، ادھیڑتی ہوئی، جہاں بچے رہ گے لوگ، اس طرح چلتے پھرتے رہے، جیسے کہ زندہ ہوں۔ (ہندی ترجمہ: اسد زیدی
انلائٹ منٹ پرجیکٹ (روشن خیالی کے پرجیکٹ) نے ہمیں سماجی علوم کے کے نئے نئے گوشوں سے آگاہ کیا، جن سے انسانی زندگی اور انسانی کارناموں کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملی، لیکن جن کے پاس ان علوم کی جاگیرداری تھی انہوں نے اس کا استعمال انسان کو انسان سے جوڑنے کے بجائے انسانوں کو بانٹنے کا کام کیا۔ لا محدود بنیادوں پر لا متناہی تنگ ثنائی خانوں میں،۔ جیسے مشرق مغرب کی ثنائیت پیدا کی ، مہذب غیر مہذب کی ثنائیت پیدا کی، افضل ابترکی ثنائیت پیدا کی۔ مذہبی ثقافتی، اور لسانی بنیادوں پرانگنت خانوں کی تشکیل کی، پھر ان میں اپنی خواہشوں کے مطابق انسانی گروہوں کو ڈال کر بند کر دیا۔ ان تفریقات نے کس کس طرح کتنی جنگوں کو جنم دیا ہے اس کا بھی ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اسی تفریقات نے انسانی دنیا کو دو عظیم (بڑی) جنگیں عنایت فرمائیں ہیں، جنوبی ایشیا میں تقسیم جیسا ہولناک سانحہ عطا کیا ہے، جس کے تباہ کن اثرات اب محسوس کئے جا رہے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تقسیم کوئی ۱۹۴۷ کی تاریخ میں قید کوئی واقعہ نہیں تھا ایک مسلسل عمل کا آغاز تھا، نفرت پیدا کرنے کا، انسانوں کے بیچ دوریاں بڑھانے کا، پنڈورا کا باکس تھا جو ۱۵ اگست ۱۹۴۷ کی ٹھیک آدھی رات سے بہت پہلے کھل گیا تھا۔
پنڈورا کو یہ باکس کس نے دیا تھا؟ ظاہر ہے برطانوی سامراج نے۔ لیکن اس باکس کی پوری ڈیزائننگ روشن خیالی پروجیکٹ (انلائٹ منٹ پروجیکٹ) کے اصولوں پر تیار ہوئی تھی۔ یہاں بھی طاقت کا مردانہ لوجک کام کر رہا تھا۔ کیونکہ مردانگی جدید ریاست کی بنیادی ضرورت ہے۔ یعنی ریاست کو طاقتور، مضبوط اور غیر جذباتی دکھنا اور ہونا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے دشمن ریاست پر غلبہ پا سکے اواس سے اپنے شہریوں کو محفوظ کر سکے۔ غیر کو دیکھنے کا بنیادی روشن خیال نظریہ اس غلط مفروضہ پر مبنی ہے کہ انسان فطری طور پر خود غرض ہوتا ہے۔
پنڈورا کون تھی؟ وہ پہلی عورت تھی جس نے پرومتھیس کے ساتھ مل کر دیوتاوں سے آگ کا علم چوری کیا تھا۔ پینڈورا کی یہ کہانی کہیں مذکور نہیں ہے،جو کہانی یونانی افسانوی روایات میں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب پرومتھیس نے آگ کا علم دیوتاوں سے چوری کرکے انسانوں میں عام کر دیا تو دیوتاوں کو اس پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے سزا کے طور پر پرومتھیس کو قوقاز کے پہاڑپر زنجیر میں مقید کرکے وحشی پرندوں کو اس کا سر نوچ نوچ کر کھانے کے لئے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اتنی ساری یاتناوں کے باوجود بھی پرومتھیس نے دیوتاوں سے معافی نہیں مانگی۔ یہ علم کی جاگیرادی کے خلاف پہلی لڑائی تھی اور پرومتھیس اس کا پہلا شہید۔
انسانوں کو سزا دینے کے کئے دیوتاوں نے ایک دوسری ترکیب اپنائی۔ انہوں نے ایک عورت کی تخلیق کی اور اس کو دنیا کی ساری نسوانی خوبیاں عطا کیں جیسے جسمانی خوبصورتی اور جنسی کشش۔ اسی طرح اس کو ساری عیاری اور مکاری بھی سکھائی گئی، پھر اسے پرومتھیس کے بھائی امفتھیس کے پاس بطور انعام بھیج دیا گیا۔ اس عورت کا نام پنڈورا تھا۔ مفتھیس نے اس سے شادی کرلی۔ پنڈورا کے پاس ایک باکس تھا جسے دیتاوں نے اسے دیا تھا۔ ایک دن پنڈورا نے اس باکس کو کھول دیا جس کے کھلتے ہی زمین پرتباہی اور بدبختی بکھر کر پھیل گئی۔ باقی رہ گئی توصرف ایک امید۔ اور اس طرح دیوتاوں نے اپنے کرتوتوں کا سارا الزام ایک عورت کے سر ڈال دیا اور اس طرح عورت انسانی کہانیوں میں گناہوں کی علامت بن کر زندہ رہی۔ افسانوی روایات میں کہانی اسی طرح لکھی ہے۔لیکن اس کہانی کو کچھ اس طرح ہونا چاہئے کہ جس میں پنڈورا نوع انسانی کے لئے بطور سزا نہ ہو بلکہ اس کو آگ کی چوری میں پرومتھیس کا ساتھ دینے کے جرم میں دیوتاوں نے سزا دی ہو۔
علم کی جاگیرداری اور طاقت کے استعمال میں اخلاقیات کے فقدان کے خلاف لڑائی میں مردانہ کردار کے مساوی نسوانی کردار کا بھی ہونا ضروری ہے، بلکہ اس موڈرنیٹی کے بےہودہ مردانگی کے خلاف نسوانیت ہی ایک واحد ہتھیار ہے۔ مرانگی سے میری مراد وہ صفات ہیں جو جنگ کی منطق سے وابستہ ہیں، جیسے بہادری، دلیری، جان بازی، قوت، مکھرتا، حفاظت، تشدد، عقل پرستی وغیرہ وغیرہ، جبکہ نسوانیت سے مراد وہ انسانی صفات ہیں جو پیار کی منطق کے ساتھ وابستہ ہیں، جیسے محبت ، شفقت، رحم دلی، نرم دلی ہمدردی، انسیت، اور جذباتیت وغیرہ وغیرہ۔ جدید ریاست کی پوری گرامر مرادانہ صفات اور جنگی منطق پر مبنی ہے،جہاں نسوانی صفات کی کوئی افادی قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ ساری صفات کمزوری کی علامات تصور کی جاتی ہیں۔ مردانگی کی سماجی ضرورت اور جبر جہاں عورتوں کو صنف کمتر اور نازک سمجھتی ہے وہیں پر اس مردانگی کے سماجی جبر کا شکار مرد بھی ہوتے ہیں۔ ۱۹۸۷ میں مردانگی کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آئزلر اور سکڈمور نے مردانہ تناو کا تصور پیش کیا۔ ان کے حساب سے مردانگی کے تین بنیادی عناصرمردوں میں اکثر جذباتی تناؤ کا باعث بنتے ہیں
جسمانی طور سخت اور مضبوط دکھنے کا سماج کا جبری تقاضہ
جذباتی تصورکئے جانے کا ڈر، یعنی جذبات کے اظہار کا خوف
بہتر مالی حیثیت کی حصولیابی اور جنسی عمل میں بہتر کارکردگی کا سماجی دباو، دوسرے لفظوں میں غربت اور مردانہ کمزوری کا ڈر
اسلام میں بھی اللہ کے صفاتی نام دو طرح کے پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جن سے خوف پیدا ہو، جیسے الجبار، القہار، الستار، القابض، الباسط، القوی وغیرہ۔ دوسرے وہ جن سے محبت اور شفقت کا اظہار ہوتا ہے جیسے الرحمن، الرحیم، الغفور، الحلیم، الغفار، الکریم، العفو، الصبور وغیرہ وغیرہ۔ صوفیا نے اللہ کی صفت رحیمیت پر زیادہ زور دیا جبکہ فقہا کی کتابوں میں اللہ کی صفت قہاریت پرزیادہ زور ہے۔ اسی لئے جب جدیدیت کی جارحیت کے خلاف جرمن رومانیت کا ظہور ہوا تو اس تحریک کے دانشوروں نے صوفیا کی کتابوں کی طرف رجوع کیا۔ خاص طور پر حافظ رومی اور خیام۔ امریکہ اور یوروپ میں مشینی زندگی سے اوب چکے لوگوں کا آخری سہارا رومی ہی ہیں۔ہندوستان میں گاندھی نے جدیدیت کے مردانہ جارحیت اورتشدد کا جواب اہمسا یعنی عدم تشدد سے دیا اور جنگی منطق پر مبنی سیاست کے بجائے دوستی، محبت اور تعاون کی سیاست کو ترجیح دی۔ اہمسا تقریبا سارے ہندوستانی مذاہب کا بنیادی تصور ہے۔
مجھے لگتا ہے پرومتھیس کو جن گناہوں کی سزا ملی انہیں گناہوں کو دہرانے سے روشن خیالی کے بطن سے پیدا ہوئی موجودہ پر تشدد سیاست اور بے مہار ترقی کی رفتار کو متوازن کیا جا سکتا ہے۔
پرومتھیس کا پہلا گناہ تھا علم پر سے دیوتاوں کی اجارہ داری ختم کرکے اس کو جمہوری بنانا
دوسرا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار۔ کیونکہ کہانی کی تفصیل میں چوری کی وجہ کا بھی ذکر ہے۔ شروع شروع میں دیوتا انسانوں کے بھوج میں شریک ہواکرتے تھے لیکن کھانے کا بیشتر اور بہتر حصہ دیوتا کھا جاتے تھے اور اپنے بھوج میں انسانوں کو کبھی بلاتے بھی نہیں تھے۔ دیوتاوں کی یہ حرکت پرومتھیس کو کھٹکتی تھی۔ اس کو لگتا تھا یہ دیوتاوں کا انسانوں پر ایک طرح کا ظلم ہے۔ اور یہیں سے اسے انسانوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگئی۔ اسی ہمدردی کے مارے اس نے بھوج میں گوشت کی تقسیم کا ذمہ خود لے لیا لیکن پرومتھیس کے طریقہ تقسیم سے دیوتاوں کا سردار زیوس ناراض ہو گیا اور اس نے دنیا سے آگ کو غائب کردیا یا یوں کہیں کہ انسانوں سے آگ کی نعمت چھین لی۔ ظاہر ہے یہ حالت انسانوں پر سخت گزری ہوگی۔ ٹھیک اسی لمحہ پرومتھیس نے آگ چوری کر کے انسانوں میں عام کردیا۔ انسانوں کے ساتھ ہمدردی پرومتھیس کا دوسرا گناہ تھا۔ اس نے دیوتاوں کے سارے ظلم سہے لیکن اس نے ان گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ آج پھر اسی جرآت گناہ سے علم طاقت اور تسخیر کے بیچ آپسی رشتہ کواخلاقی بنیادوں از سر نو تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ خدایا ہمیں ان گناہوں کو کرنے کی توفیق دے۔
زندگی کے نام پر بس اک عنایت چاہیئے۔۔۔۔ مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیئے
تبریز احمد